
-
فرمان الہی
-
نماز کے اوقات
- پیر5؍ رمضان المبارک1447ھ23؍ فروری 2026ء
- بانی: میرخلیل الرحمٰن
- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

 فرمان الہی
فرمان الہی
 نماز کے اوقات
نماز کے اوقات


بات چیت: زیب النّسابرکی
ترجمہ: طلعت عمران
اکتوبر کی ایک گرم سہ پہر، پروفیسر ڈاکٹر کلارک میک کولی کے ساتھ ہونے والی ایک مختصر سی ملاقات، انتہا پسندی کی نفسیات، اِس کی جڑوں، حقائق اور اسے گھیرے میں لیے فرضی و افسانوی باتوں کے ایک جاذبِ توجّہ سفرمیں تبدیل ہوگئی۔ ڈاکٹر میک کولی ایک امریکی سماجی نفسیات دان ہیں اور طویل عرصے سے برین مور کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔
اُنہوں نے اپنی زندگی کی کئی دہائیاں گروہی حرکیات، نسلی تنازعات کے دقیانوسی تصوّرات اور نفسیاتی بنیادوں، دہشت گردی اور نسل کُشی کا مطالعہ کرتے گزاری ہیں۔ آج سے چند ہفتے قبل اپنے دورۂ پاکستان کے موقعے پر اُنہوں نے سیاسی تشدّد کی نفسیات پراپنی برسوں کی تحقیق اور غور و فکر سے حاصل کردہ نتائج پر بصیرت افروز گفتگو کی۔
گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو گوناگوں داخلی و خارجی عوامل کی بناء پر شدّت پسندی، دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جن پر قابو پانے کے لیے حکومت، متعلقہ ادارے اور ذرائع ابلاغ مشترکہ کاوشوں میں مصروفِ عمل ہیں۔
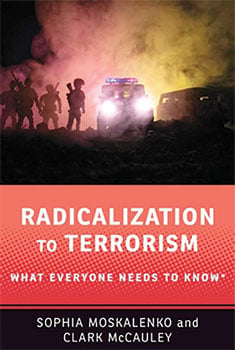
گزشتہ دنوں امریکی سماجی ماہرِ نفسیات، پروفیسر ڈاکٹر کلارک میک کولی ایک مختصر دورے پر پاکستان تشریف لائے، تو نمائندہ ’’دی نیوز‘‘ نے اُن سے اِسی اہم ، حسّاس موضوع، ’’انتہا پسندی کی تفہیم‘‘ کے ضمن میں فکر انگیز، موثر گفتگو کی۔ انٹرویو کی اہمیت کے پیشِ نظر اُس کا اُردو ترجمہ ’’جنگ، سن ڈے میگزین‘‘ کے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔
سیاسی نفسیات کو واضح کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر کلارک میک کولی کا کہنا تھا کہ ’’ہر چند کہ یہ بالعموم ہر قسم کے بین الجماعتی تنازعات سے متعلق ہے، لیکن یہ خاص طور پر تشدّد پر مبنی تنازعات سے تعلق رکھتی ہے۔ اُن کے بقول، ’’آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مَیں دہشت گردی، نسل کُشی یا سیاسی بنیادوں پر بڑے پیمانے پرقتلِ عام کے محرکات کے ضمن میں خاصا علم اور شعور رکھتا ہوں۔‘‘
جب ’’دی نیوز‘‘ نے اُن سے یہ پوچھا کہ وہ ’’انتہا پسندی‘‘ کی کیا تعریف کرتے ہیں، تو اُنہوں نے سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا کہ ہم اکثر اس اصطلاح کا استعمال مبہم انداز میں کرتے ہیں۔ ’’مَیں اس کا ایک مستقل مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
میرے نزدیک اِس کا مطلب عقائد، احساسات اور رویّوں میں رُونما ہونے والی تبدیلی ہے۔‘‘ اُن کا کہنا تھا کہ اِس لفظ کے معنی و مفہوم مزید وسیع بھی ہو سکتے ہیں۔ ’’مَیں نے محسوس کیا کہ عقائد میں انتہا پسندی اور عمل میں انتہا پسندی، دونوں مختلف نفسیاتی عوامل ہیں۔‘‘ یہ فرق مشہور ’’دواہرامی ماڈل‘‘ (مخروطی مصری مینار) کی بنیاد ہے، جو ہمیں یہ سمجھانے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور اعمال میں کیسے تبدیلی لاتے یا نہیں لاتے ہیں۔
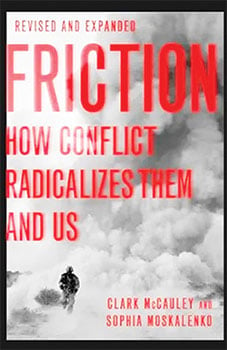
اُنہوں نے اِس ماڈل کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ’’خیالات کے ہرم میں سب سے نیچے وہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی کسی تنازعے سے متعلق کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اُس کے اوپر والے درجے میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو ہم دردی رکھتے ہیں۔ اُس سے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں، جو حمایت کرتے ہیں اور پھر اُن لوگوں کا نمبر آتا ہے، جو غیر قانونی اور ناجائز کام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں اور سب سے اوپر وہ لوگ ہیں، جو دوسری طرف کے افراد کو مار ڈالنے ہی پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔‘‘ اس کے برعکس عمل کے ہرم میں سب سے نیچے وہ لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کرتے۔ پھر وہ ہیں، جو کسی مقصد کے لیے سیاست، خدمتِ انسانیت یا تعلیم جیسے قانونی طریقوں کے ساتھ سرگرمِ عمل ہوتے ہیں۔
اِس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں، جو غیرقانونی اقدامات کرتے ہیں اور آخرمیں و ہ لوگ کہ جو قتل وغارت گری پر اُتر آتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر کلارک میک کولی خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ’’یہ مراحل نہیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی شخص سب سے زیادہ انتہا پسندانہ نظریے تک پہنچنے کے لیے پہلے والے درجات سے گزرے۔ متعدد لوگ آگے بڑھتے ہوئے فوراً کسی انتہائی قدم پر پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دوست یا عزیز کے کہنے پر سیاسی نظریات کے بغیر بھی کسی انتہاپسند تنظیم میں شامل ہوسکتا ہے۔‘‘
جب پروفیسر ڈاکٹر میک کولی سے یہ پوچھا گیا کہ لوگ انتہا پسندی کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں، تو اُنہوں نے ایک غیرمتوقّع نکتہ پیش کیا کہ اس کاسبب نفرت نہیں، بلکہ محبّت ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ’’زیادہ ترلوگ سمجھتے ہیں کہ گروہی تنازعات نفرت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن اِن کی جڑ دراصل محبّت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی قوم، مذہب یا برادری سے محبت ہوتی ہے اور یہ محبّت ہی ہمیں کم زور بناتی ہے۔
جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمیں محبّت ہے، وہ کسی دوسرے گروہ کے ہاتھوں تکلیف میں ہیں، تو ہم میں غُصّہ اور خوف پیدا ہوتا ہے اور یہی جذبات ہمیں انتہا پسندانہ خیالات یا اعمال کی طرف دھکیلتے ہیں۔‘‘ اُن کا مزید کہنا تھا کہ اِس ضمن میں معاشی محرومی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
اُن کے مطابق، ’’یہ اہم نہیں ہوتا کہ کسی کی مالی حالت کتنی اچّھی یا بُری ہے، بلکہ یہ احساس اہمیت رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا گروہ ہم سے بہتر ہے اور یہ فرق غیر منصفانہ ہے اور جب لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں سیاسی تنازع جنم لیتا ہے۔‘‘
اُنہوں نے اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ’’اس لیے انتہا پسندی صرف غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر اوقات دہشت گرد یا پُرتشدّد عناصر متوسّط طبقے سے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نظریات سے جُڑے ہوتے ہیں اور اُن دوسروں لوگوں کا دُکھ محسوس کرسکتے ہیں کہ جن کی اُنہیں فکر ہوتی ہے۔‘‘
پھر اُنہوں نے اپنی وضع کردہ اصطلاح، ’’جو جِتسو پالیٹکس‘‘ کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک ایسی حکمتِ عملی ہے کہ جس میں کم زور فریق طاقت وَر فریق کو اشتعال دلاتا ہے تاکہ وہ حد سے بڑھ کر ردِعمل دے۔ ’’ہماری دانست میں یہ دہشت گردوں کی ایک چال ہوتی ہے۔
وہ حملہ کرتے ہیں تاکہ غُصّہ پیدا ہو اور پھر توقّع کرتے ہیں کہ یہ اشتعال طاقت وَر کو زیادہ سخت ردِعمل پر مجبور کرے گا اور اس ردِ عمل سے مزید ہم دردیاں، مزید حمایت اور نئے کارکن ملیں گے۔‘‘ اُنہوں نے کہا کہ نائن الیون کے بعد امریکا کا ردِعمل اِس کی بہترین مثال ہے۔ ’’القاعدہ نے چاہا کہ امریکا براہِ راست مسلم ممالک کے خلاف میدان میں اُترے اور پھر امریکا نے پہلے افغانستان اور پھر عراق میں یہی کیا۔‘‘
جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی ریاست طاقت کے استعمال کے بغیر دہشت گردی سے نمٹنے میں کام یاب رہی ہے، تو انہوں نے 1993ء کے پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملے پر امریکی ردِعمل کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ’’امریکا کا ردِعمل اُس وقت خالصتاً فوج داری نظام پر مبنی تھا۔
ہم نے اپنے مُلک کے اندر اور بیرونِ مُلک موجود مجرموں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑا، اُن پر مقدّمات چلائے، اُنہیں سزائیں دیں اور وہ آج بھی جیل میں ہیں۔‘‘ اُنہوں نے اس کا نائن الیون کے بعد کے عسکریت پسندانہ ردِعمل سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ ’’امریکا نے دوبارہ ایسا کیوں نہیں کیا؟ میرے پاس اِس سوال کا کوئی مناسب جواب نہیں ہے۔‘‘
جب ’’دی نیوز‘‘ نے اُن سے پوچھا کہ کیا ریاستیں وقت کے ساتھ زیادہ سیکیورٹی پر مشتمل ہوگئی ہیں، تو اُنہوں نے کہا کہ ’’برطانیہ کا پریوینٹ پروگرام ہے اور انہوں نے اساتذہ کو بھی ریاستی سلامتی کا ایجنٹ بنانے کی کوشش کی ہے۔‘‘ اس ضمن میں انہوں نے مزید کہا کہ یہ رجحان نائن الیون کے بعد پیدا ہونے والے خوف سے پیدا ہوا۔ ’’یورپ کے ہر مُلک نے کسی نہ کسی بہانے سے سیکیورٹی بڑھائی۔
کبھی ضرورت سے زیادہ بھی… چند بُرے افراد کے اعمال پورے مُلک کو مسلمانوں کے خلاف کردیتے ہیں اور ریاست گرفتاریوں پر اُتر آتی ہے۔‘‘ اُنہوں نے لی پَین اور فرانس کےحوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’فرانس میں لی پَین جیسے سیاست دانوں کی سیاست کا مسلمانوں کے یک جا ہونے پر کیا اثر ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ایک دن نئی ہم دردی، نئی حمایت اور نئے بھرتی ہونے والے جنم لیں گے۔‘‘
جب ان سے انتہاپسندانہ آراء پر بڑھتے ہوئے ارتکازیعنی لوگوں کے آن لائن انتہا پسندانہ خیالات کے محض اظہار سے متعلق استفسار کیا گیا، تو ڈاکٹر مک کولی نے تسلیم کیا کہ ’’یہ اب ایک نیا نصب العین بن گیا ہے، لیکن دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے یہ طریقہ بہت غیر مؤثراور ناکارہ ہے، کیوں کہ اس کی تمام تر توجّہ خیالات پر ہے، عمل پر نہیں۔‘‘
پھر ہماری گفتگو کا رُخ میڈیا کے بیانیوں کی طرف ہوا۔ اور جب ہم نے اُن سے پوچھا کہ کیا صحافت انتہاپسندی یا انتہاپسندانہ نظریات کو بڑھاوا دے رہی ہے، تو اُنہوں نے پہلے ان اصطلاحات میں پائے جانے والے ابہام پر اعتراض کرتے ہوئے جواب دیا کہ ’’نظریے یا بیانیے کی کوئی متفقہ تعریف نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں نے نظریے کو عوامی سروے میں ماپنے کی کوشش کی ہے۔
لہٰذا، میرا ماننا یہ ہے کہ سماجی تحاریک کے نظریے سے تین تصوّرات اخذ کیے گئے ہیں، جو زیادہ مخصوص و متعیّن اور قابلِ پیمائش ہیں اور یہ تصوّرات ترغیبی، تشخیصی اور قابلِ پیش بینی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ’’تشخیصی نظام میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا ذمّےدار کون ہے؟
قابلِ پیش بینی تصوّر میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تشدّد، سیاست، تعلیم یا خدمت؟ جب کہ تحریکی فارمولا یہ استفسار کرتا ہے کہ کِسے اور کیوں عمل کرنا چاہیے؟‘‘ اُنہوں نے کہا کہ ان تصوّرات سے بہتر انداز میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ میڈیا انتہا پسندانہ بیانیوں کو کیسے مضبوط یا کم زور کرتا ہے۔ اُنہوں نے مزید کہا کہ ’’یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس میڈیا کی بات کررہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب کچھ موجود ہے۔ انتہائی پُرامن مواد سے لے کرانتہائی نفرت انگیز اور پُرتشدّد مواد بھی۔‘‘
امریکی سماجی نفسیات داں سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا صحافت انتہاپسندی جیسے پیچیدہ موضوعات کو حد سے زیادہ آسان بنا دیتی ہے، تو اُنہوں نےکہاکہ ’’عمومی طور پر میڈیا حکومت کے حق میں ہوتا ہے۔‘‘
پھر اُنہوں نے اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ’’ابتدا میں جب آئرش ری پبلکن آرمی کی خبر دی جاتی تھی، تو اُسے ہمیشہ ’’دہشت گرد‘‘ کہا جاتا تھا۔ پھر اُنہیں ’’جنگ جُو‘‘ کہا جانے لگا۔ گویا وقت گزرنے کے ساتھ میڈیا کم متعصّبانہ اور کم حکومتی لہجہ اپنانے لگا۔‘‘
گفتگو کے اختتام پرجب ’’دی نیوز‘‘ نے پروفیسر ڈاکٹر کلارک میک کولی سے پاکستان سے متعلق اُن کے تاثرات جاننا چاہے، تو وہ مُسکراتے ہوئے بولے کہ ’’پانچ یا چھے دن میں ماہر بننا مشکل ہے، لیکن مَیں نے یہاں کی نسلی، لسانی اور تاریخی تقسیم کی پیچیدگیوں اور 1947ء میں یہاں آنے والوں اور پہلے سے موجود لوگوں کے درمیان فرق کے بارے میں خاصی آگہی حاصل کی ہے اور یہاں اپنے قیام کے دوران نوجوانوں سے مل کر مُجھے اس مُلک کے لیے ایک امید اور اُمنگ کا احساس ہوا ہے۔