
-
فرمان الہی
-
نماز کے اوقات
- منگل 20؍ رمضان المبارک 1447ھ10؍مارچ 2026ء
- بانی: میرخلیل الرحمٰن
- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

 فرمان الہی
فرمان الہی
 نماز کے اوقات
نماز کے اوقات


ادب کی تقویم میں زمانے اپنی آوازوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ آوازیں اپنے عہد کے طرزِ احساس، انسانی تجربے اور اجتماعی شعور کے ذریعے اپنے دور کے نقوش اجاگر کرتی ہیں، جو ایک عہد کے امتیاز اور تاریخ کے ایک باب کا تعین کرتے ہیں۔
بیسویں صدی میں ہمارے ادبی اُفق پر جن آوازوں کے رنگ طلوع ہوئے ان میں تین نام ناصر کاظمی، انتظار حسین اور جمیل الدین عالی بھی ہیں۔ ناصر کاظمی شعلۂ مستعجل تھے۔ وہ بہت جلد رخصت ہوگئے جب کہ مؤخر الذکر دونوں نے اچھی عمر پائی اور ایک طویل دور کے گرم و سرد دیلھے۔ ان تینوں افراد میں ایک قدرِ مشترک تو یہ ہے کہ ۲۰۲۵ء ان کی ولادت کا سو واں سال ہے۔
دوسرے یہ کہ ان کی ساخت پرداخت اور شناخت کا زمانہ ایک ہے اور ہمارے جن دو بڑے اجتماعی تجربات نے ان کے تخلیقی شعور پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، وہ ہمارے ملک کا قیام اور اس کا دو لخت ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا باہمی ربط ضبط بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ذیل میں ان کے بارے میں مختصرا ملاحظہ کیجئے۔
٭……٭٭……٭٭……٭
شب ہجراں کے سائے، ناصر کاظمی
ہمارے ہم عمروں، ہم عصروں کو ناصر کاظمی کو پڑھنے اور کچھ ریکارڈنگز کے ذریعے سننے کا موقع تو ملا لیکن ان کی ہم بزمی میسر نہیں آئی۔ ناصر کاظمی نے محض ایک شاعر یا ایک شعری لہجے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک زندہ طرزِ احساس کے طور پر ہمارے حافظے میں جگہ پائی۔ لگ بھگ پانچ عشروں پر مشتمل ہماری یادداشت کی تختی پر اس نقش کی دمک آج بھی اوّل اوّل کی محبت جیسی ہے۔
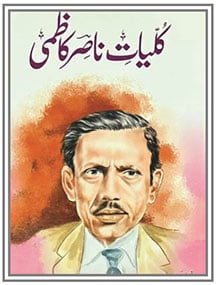
شاعری کے بعد ناصر کاظمی کی یاد آوری کے دو حوالے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ ایک ان کی شب بیداری یا کہہ لیجیے، رات بھر کی آوارہ خرامی، دوسرے ہنستے گاتے پرندوں، سوچتے بولتے درختوں، سرکتے سمٹتے موسموں، رنگ بے رنگ ہوتے مناظر سے والہانہ وابستگی۔
ناصر کاظمی کی شخصیت کے ان دونوں حوالوں کی بابت کم و بیش ان کےسب ہی ساتھیوں نے لکھا ہے، تاہم انتظار حسین نے اپنے دوست کی زندگی کے اس رُخ پر سب سے زیادہ روشنی ڈالی اور کیوں نہ ہو کہ سب سے بڑھ کر وہی تو ناصر کاظمی کے ساتھ لاہور کی سڑکوں کا گز بنے شہر کی لمبان ناپتے جانچتے رہے تھے۔
انتظار حسین تو خیر ہم دم تھے اور پھر ادیب بھی، سو انھوں نے اپنے یار طرح دار کو طرح طرح سے یاد کیا اور یوں کہ ایک شخص کی یاد کو ایک شہر اور ایک عہد کی یاد بنا دیا۔ ناصر کاظمی کی آسیب کی طرح بڑھتی بیماری اور اس کوچہ و بازار دنیا سے بہ عجلت روانگی نے انھیں کچھ ایسا افسانہ و افسوں بنایا کہ دوستوں، شاعروں اور ادیبوں کے علاوہ لاہور میں رات گئے تانگا چلاتے کوچوان اور چائے خانوں کے میزبان بھی انھیں یاد کرتے پائے گئے۔
ناصر کاظمی نے اپنے آخری دنوں میں انتظار حسین سے گفتگو کرتے ہوئے ایک کوچوان کا واقعہ کچھ یوں سنایا تھا: ’’ایک رات بارش ہوئی تو میں بھی اٹھ کر گھر کی طرف چلا۔ ایک تانگے والے کو دیکھا۔ پوچھا، کیا میرے گھر تک چلو گے کرشن نگر۔ اس نے جواب دیا، میں نے بڑی بڑی سواریوں کو منع کر دیا ہے، اس برکھا میں کون جائے گا۔ میں نے کہا، بھائی میں شعر کہتا ہوں۔ بولا، اچھا، اپنا کوئی شعر سنائو۔ میں نے شعر سنایا:
واقعہ یہ ہے کی بدنام ہوئے
بات اتنی تھی کہ آنسو نکلا
وہ بڈھا تانگے والا اچھل گیا۔ بولا، ابے لمڈے یہ تیرا شعر ہے۔ آ بیٹھ تانگے میں، تجھے ساری عمر مفت گھر لے کر جاؤں گا۔ ‘‘ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ آخری وقت تک ناصر کاظمی کو گھر چھوڑ کر آتا رہا۔
بلاشبہ یہ شعر کی برکت ہے، اور یاد رہے کہ یہ برکت ہماشما کے حصے میں نہیں آتی، ناصر کاظمی ایسوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔
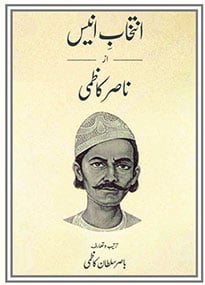
ناصر کاظمی کوئی گم سم یا مست ملنگ آدمی نہیں تھے، ان کے اندر زندگی لہریں لیتی تھی۔ دوستوں کی محفل میں چہکتے اور برمحل بذلہ سنجی سے بھی کام لیتے۔ ایک بزم میں کوئی صاحب ان سے آ کر ملے۔ وہ بھی شعر گو تھے۔ ناصر کاظمی سے بولے، میں آپ کو بڑا مداح ہوں۔ کسی اخبار یا رسالے میں آپ کی غزل چھپتی ہے تو باربار پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں، کاش اس غزل پر میرا نام ہوتا۔
ناصر کاظمی نے شکریہ ادا کیا۔ وہ صاحب کچھ اور حوصلہ مند ہوئے، بولے، میری شاعری آپ کی نظر سے گزری؟ اثبات میں جواب پاکر انھوں نے پوچھا، میری غزل دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے؟
ناصر کاظمی نے برجستہ جواب دیا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پر آپ ہی کا نام درج ہے۔
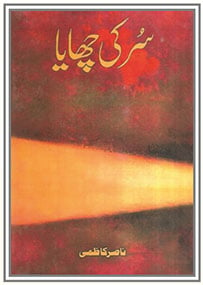
ناصر کاظمی، جدید اردو غزل کا ایک معتبر اور اہم باب ہے۔ ان کے یہاں ایک طرف میر کا آہنگ تأسف اور حزن کی لے ابھارتا ہے تو دوسری طرف اپنے عہد میں فطرت کے اڑتے، بدلتے رنگ اور جذبۂ انسانی کی بے مایگی اور شکستگی کا گہرا احساس ان کی شعری تشکیلات کے بنیادی عناصر ہیں۔
ناصر کاظمی کے یہاں ایک طرف اپنی تہذیب و روایت کا شعور اور اس سے جڑے رہنے کی آرزو نمایاں ہے تو دوسری طرف عہدِ جدید کے مضطرب و مضمحل انسان کی کیفیت اور اپنی اصل سے دوری کا احساس اُبھرتا ہے۔
ان کی غزل اپنی کلیت میں متضاد سمتوں کی جانب کھنچتے اور پلٹتے انسان کے جذبہ و احساس کو گرفت کرنے سے عبارت ہے۔ یہ شاعری اپنے قاری کو ایک ایسے گداز سے ہم کنار کرتی ہے جو زندگی کے ہمہ جہت شعور سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر کہیں گہرائی میں ایک ہوک سی پیدا کرتا ہے۔
کچھ شعر ملاحظہ کیجیے:
نیتِ شوق بھر نہ جائے کہیں
تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں
———
میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر
وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے
———
ترے قریب رہ کے بھی دل مطمئن نہ تھا
گزری ہے مجھ پہ یہ بھی قیامت کبھی کبھی
———
گرفتہ دل ہیں بہت آج تیرے دیوانے
خدا کرے کوئی تیرے سوا نہ پہچانے
———
امیدِ پرششِ غم کس سے کیجیے ناصرؔ
جو اپنے دل پہ گزرتی ہے کوئی کیا جانے
٭……٭٭……٭٭……٭
تقدیر و تہذیب کی راہ پر ، انتظار حسین
گزشتہ پون صدی میں اردو کے جن معدودے چند ادیبوں نے تادمِ آخر مثالیت کے درجے میں مسلسل سرگرم زندگی بسر کی ان میں ایک نام انتظار حسین کاہے۔ توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں سرگرمی کا دائرہ محض اپنی ذاتی کارگزاری تک محدود نہیں ہے بلکہ اجتماعیت کے زاویے سے بھی دیکھیے تو وہ اپنے عصری ادبی منظرنامے میں بھی ایک بھرپور اور ہمہ جہت کردار ادا کرتے ہوئے ملتے ہیں۔
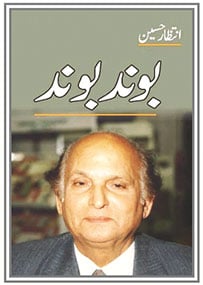
انتظار صاحب سے اوّل اوّل ہماری صاحب سلامت اور بعدازاں قربت اور ’دوستی‘ کا عرصہ یہی کوئی ساڑھے تین دہائیوں کو محیط ہے۔ دوستی ان معنوں میں کہ زندگی کے آخری تیس پینتیس برسوں میں انھوں نے اپنے جن دوچار جونیئر معاصرین سے ایک خاص الطاف و التفات کو روا رکھا، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ ان کی بابت یہ تأثر عام تھا کہ وہ سب سے بے تکلف نہیں ہوتے اور یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی۔
کسی سے بھی ملنے ملانے یا بات چیت میں انھیں کچھ باک نہ تھا، لیکن قہقہہ بار وہ کم ہی لوگوں کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ ہماری پہلی ملاقات انتظار صاحب کے ساتھ پاک ٹی ہاؤس، لاہور میں ہوئی تھی۔ یہ گزشتہ صدی کی اسّی کی دہائی کے ابتدائی برسوں کا واقعہ ہے۔ پاک ٹی ہاؤس اس زمانے میں ادیبوں کی خاص بیٹھک تھی۔
یہ وہ دور تھا جب ہماری سماجی زندگی میں گفتگو یا مکالمہ ایک قدر کا درجہ رکھتا تھا۔ متضاد خیالات کے لوگ بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ادبی دنیا کی تو فضا یہ تھی کہ یہاں ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بنانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ چناں چہ باہم متصادم تصورات و نظریات کے لوگ بھی ایک میز پر آ بیٹھتے۔ دھواں دھار بحث مباحثہ رہتا، اختلاف کی گرمی دیدنی اور شنیدنی ہوتی، لیکن ان میں کسی چیز کو بھی طرفین ذاتی مسئلہ نہ بناتے، کوئی بحث یا اختلاف باہمی انسانی مراسم پر اثرانداز نہ ہوتا۔
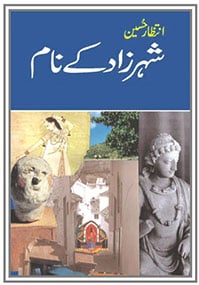
لاہور کا پاک ٹی ہاؤس ایسی ہی سرگرمیوں کا خاص مرکز تھا اور انتظار حسین اس سے گہری وابستگی رکھنے والے لوگوں میں تھے۔ ہمیں اسی ٹی ہاؤس میں ان کی گرما گرمی کے واقعات کی چشم دید گواہی کا موقع ملا۔ یوں تو ان کے کالم کی زد میں سلیم احمد، جمیل الدین عالی، منیر نیازی، اشفاق احمد، کشور ناہید، مظفر علی سیّد، زاہد ڈار، اکرام اللہ، احمد بشیر، حمید نسیم، اعجاز حسین بٹالوی غرضے کہ کون نہیں آیا، لیکن انتظار حسین کے سب سے زور دار مچیٹے انور سجاد کے ساتھ رہے۔ یہ ترقی پسندوں اور اہلِ روایت کے ٹکراؤ کا دور تھا۔
انور سجاد خم ٹھونک کر اور ترقی پسندوں کا علم اٹھا کر میدان میں اترے ہوئے تھے اور ادھر انتظار حسین اہلِ روایت کے نمائندے تھے۔ کیا کیا مباحث رہتے تھے کہ جن سے ہم ایسے خوردوں کو بہت کچھ سیکھنے کی فضا میسر آتی۔ افسوس، اب وہ لوگ رہے اور نہ وہ باتیں۔
انتظار صاحب کی طبیعت میں چھیڑ خوباں سے رکھنے کا خاص ذوق پایا جاتا تھا۔ وہ بلاتأمل اس کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ وہ بھلا کیا ادیب ہوا جو ایک کونے میں بیٹھ کر افسانہ یا مضمون لکھ رہا ہے، ادیب کو تو اختلاف اور ٹکراؤ سے تحریک ملتی ہے۔ اسے گوشہ گیر نہیں ہونا چاہیے۔
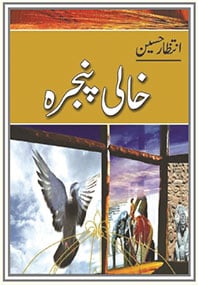
لطف کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف وہ ادیب کی اس آزادی کے بھی خواہاں تھے کہ وہ معاشرے کے ہر واقعے کا نوٹس لینے کا پابند نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک واقعہ آج ہو اور ادیب کا اس پر تأثر یا ردِعمل برسوں بعد ہمارے سامنے آئے۔ اس لیے کہ ادیب کے اندر چیزیں اپنے انداز سے جگہ پاتی ہیں اور ان کے بارے میں اس کا رویہ تشکیل پانے میں وقت طلب بھی ہو سکتا ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ انتظار حسین کے فکشن میں ہمیں ادیب کے رویے کی دونوں مثالیں ملتی ہیں۔ انھوں نے اپنے عہد کے قومی و اجتماعی واقعات کو کبھی جلد اور کبھی بدیر اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا۔ مثال کے طور پر پاکستان کا دو لخت ہونا ان کے یہاں افسانوں میں فوری طور پر اور ناول میں بعدازاں سامنے آیا۔
دہشت گردی، سیاسی اتھل پتھل، بدلتا اخلاقی، تہذیبی منظرنامہ بھی اسی طرح ان کے یہاں ملتا ہے۔ تاہم یہ بات پوری ذمہ داری سے کہی جاسکتی ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی کا شاید ہی کوئی ارتعاش ایسا ہو جسے انھوں نے نظرانداز کیا ہو۔ جس انداز سے اپنے معاشرے اور اس کے معاملات اور معمولات پر ان کی نظر رہی، اس عہد کے کم ہی ادیبوں کی رہی ہوگی۔
انتظار حسین ہماری تہذیبی زندگی کے اس دور کی یادگار تھے جب ہمارے یہاں ادیب ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک نہیں، کئی ایک شعبوں میں اپنی اہلیت کا ثبوت دیتےاور اپنی استعداد کا اظہار کرتے، انہوں نے صرف فکشن تخلیق نہیں کیا، بلکہ صحافت بھی کی، اپنے عہد کے ادب اور ادیب کی وہ روداد لکھی جو بلاشبہ ثقافتی و تہذیبی تاریخ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی ادب و فکر کے ایسے تراجم بھی کیے جو انسان اور اس کی اجتماعی صورتِ حال کو مختلف ثقافتوں کے تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔
فکشن انتظار حسین کا بنیادی سروکار ہے اور اس شعبۂ ادب میں انھوں نے اَن مٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کے افسانوں اور ناولز دونوں کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے، یہ بات پوری دیانت اور وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ انھوں نے اپنے تخلیقی تجربات کے ذریعے ان اصناف کی مروّجہ رسمی اور تدریسی تعریف میں اس طرح توسیع کی کہ اس کو یکسر بدل ڈالا۔
انتظار حسین کے تخلیقی سفر کا آغاز روایتی انداز کا تھا اور اس میں سماجی حقیقت نگاری نمایاں تھی، لیکن تھوڑا سا ہی آگے چل کر انھوں نے نو بہ نو وسعتوں کا سراغ پا لیا۔ اردو افسانے کی تاریخ ’’آخری آدمی‘‘، ’’کایا کلپ‘‘، ’’زرد کتا‘‘، ’’کٹے ہوئے ڈبے‘‘، ’’صبح کے خوش نصیب‘‘ اور ’’مورنامہ‘‘ ایسی تخلیقات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ناول ’’بستی‘‘ کی ہجرت درحقیقت ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے ایک عہد کی ہجرت کا ماجرا بن جاتی ہے۔ بعدازاں ان کے ناول ’’آگے سمندر ہے‘‘ میں ایک مرکزی کردار ’مجو بھائی‘ کی گم شدگی ایک تہذیب کی گم شدگی کا استعارہ ہو جاتی ہے۔
انتظار حسین ایک ایسے ادیب تھے جو اپنی انفرادی زندگی اور فن کے توسط سے پورے عہد کا صورت گر نظر آتا ہے۔
٭……٭٭……٭٭……٭
کہیں تو ہوگی ملاقات اے چمن آرا، جمیل الدین عالی
جمیل الدین عالی صاحب سے ابتدائی ملاقاتیں کچھ ایسی نہ تھیں کہ ذاتی مراسم کی صورت بنتی، لیکن بعدازاں کچھ اس نوع کے واقعات ہوئے جن میں ان کی ملنسار اور وضع دار شخصیت کے بعض بڑے دل گداز پہلو سامنے آئے کہ عمر کے تفاوت کے باوجود ایک طرح کی دوستی کی راہ کھلتی چلی گئی۔
وہ تھے ہی اس وضع کے آدمی کہ اگر کہیں تعلق ہو جاتا تو اسے اپنے انداز میں اور اپنی ایک خاص وضع سے نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کے اس پہلو کی بابت یہاں ایک واقعہ سنیئے۔
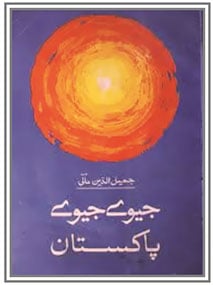
افسانہ نگار اور شاعر،عرش صدیقی صاحب ملتان سے کراچی آئے تھے۔ وہ بہت نفیس اور خلیق انسان تھے۔ نوجوانوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اُس وقت اُن کی کراچی آمد کا سبب علاج تھا، انھیں کینسر ہوگیا تھا۔ کراچی آکر انھوں نے عالی صاحب سے رابطہ کیا۔
دونوں میں رائٹرز گلڈ کے زمانے سے گہرے مراسم تھے۔ عالی صاحب نے اسی رات یا شاید اگلے دن عشائیے پر انھیں مدعو کیا اور دریافت کیا کہ اگر وہ کسی اور کو بھی اس دعوت میں شریک کرنا چاہیں تو بلاتکلف بتائیں۔ عرش صدیقی صاحب نے ہمارا نام لیا ہوگا، جس پر عالی صاحب نے صاد کیا۔ کراچی جم خانہ میں دعوت رکھی تھی۔
دونوں چوں کہ پرانے دوست تھے اس لیے گفتگو میں پھلجھڑیاں سی چھوٹ رہی تھیں۔ عالی صاحب تو کسی قدر تیکھے فقرے بھی لگا رہے تھے۔ ہمیں اُس وقت عرش صاحب اور عالی صاحب کے دیرینہ اور بے تکلّفانہ مراسم کا بالکل اندازہ نہ تھا۔ اس لیے عرش صاحب سے ان کی چھیڑ چھاڑ ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فقرے بازی کا یہ معاملہ یک طرفہ چل رہا تھا، یعنی عرش صدیقی صاحب پلٹ کر فقرہ نہیں دے رہے تھے، حالاںکہ وہ بھی زندہ دل اور بذلہ سنج آدمی تھے۔
گو کہ وہ بیماری کو اعصاب پر سوار کیے ہوئے نہیں تھے اور بہت ہمت سے کام لے رہے تھے، لیکن اُن کی بشاشت بہرحال متأثر تھی۔ اُن کی اس کیفیت سے دل کٹنے لگا اور عالی صاحب کی شگفتگی سخت ناگوار ہوئی۔ چناں چہ اُن کے کسی شوخ فقرے پر ہم پلٹ پڑے۔
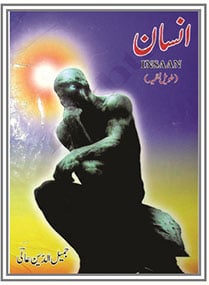
انھیں یقینا اس غیر متوقع دخل در معقولات پر تعجب ہوا ہوگا کہ جبھی انھوں نے پل بھر کو تأمل کیا اور بولے، ’’بھئی مرزا صاحب! عرش بھائی آپ کے استاد ہوں گے، لیکن میرے تو ساٹھ کی دہائی سے دوست ہیں۔ میں اِن کی عزت کرتا ہوں اور اِن سے محبت بھی کرتا ہوں، اور میری ان سے بے تکلفی ہے۔‘‘
ہم نے کہا، ’’صاحب یہ بھی خوب ہے کہ آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہیں اور اسے بندوق کی نال پر بھی رکھے ہوئے ہیں۔‘‘
اس سے پہلے کہ عالی صاحب ہمیں جواب دیتے اور ہمارے درمیان باقاعدہ محاذ کھل جاتا، عرش صاحب نے ہمارے تیور بھانپ لیے۔ بولے، ’’ارے مبین مرزا، عالی صاحب میرے بہت پرانے اور بہت محبت کرنے والے دوست ہیں۔ میں تو ان کی باتیں انجوائے کررہا ہوں۔‘‘ پھر وہ عالی صاحب سے مخاطب ہوئے، ’’عالی صاحب، مبین مرزا مجھے بہت عزیز ہیں اور یہ بھی مجھ سے تعلقِ خاطر رکھتے ہیں۔‘‘
’’عرش بھائی، وہ تو مجھے اندازہ ہورہا ہے۔ مرزا صاحب آپ کے چہیتے شاگردوں میں ہیں۔‘‘
’’نہیں عالی صاحب، مبین مرزا میرے شاگرد نہیں ہیں۔‘‘ عرش صدیقی صاحب مسکرائے اور ہماری طرف دیکھ کر بولے، ’’یہ میرے شاگرد ہوتے ہوتے رہ گئے۔ انھوں نے انگریزی ادب میں داخلہ تو لیا، مگر ملتان میں نہیں، لاہور جاکر، ویسے یہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں۔‘‘
’’عرش بھائی! ایسی محبت کا رشتہ بس تعلیم کے شعبے کے لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔‘‘ عالی صاحب کے لہجے میں رشک نمایاں تھا۔
’’عالی صاحب! یہ بھی قدرت کی دَین ہے۔ اس شعبے میں بھی اب وہ بات نہیں رہی اور اگلے وقتوں کی عزت محبت اب سب کو میسر نہیں۔‘‘
اب گفتگو کا رُخ مڑ چکا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد عالی صاحب، عرش صاحب سے ان کی بیماری کی تفصیلات دریافت کرنے لگے۔ پھر پوچھا، آپ نے اپنا کوئی چیک اپ کرایا ۔ عرش صاحب نے نفی میں جواب دیا۔ عالی صاحب نے بتایا کہ انھوں نے شوکت خانم اسپتال کی بہت تعریف سنی ہے، ایک بار وہاں جاکر ضرور دکھائیں۔
عالی صاحب نے ایک رقعہ لکھا، انھیں رُقعہ نویسی کرتے ہوئے دیکھ کر خیال ہوا کہ وہ جتنے نیک دل ہیں اتنے ہی بدخط ہیں۔ سطریں آڑیں ترچھی اور خط یا مظہر العجائب! عبارت کو دیکھ کر بس یوں لگتا تھا جیسے مکھی کی ٹانگ کو روشنائی میں ڈبو ڈبو کر بادلِ نخواستہ خطاطی کی مشق کی گئی ہے۔
عرش صدیقی صاحب سے اُن کی بیماری کی تفتیش اور اس سارے سلسلے میں جس والہانہ پن سے عالی صاحب نے دستِ تعاون پیش کیا تھا، جس طرح اسپتال سے فوری رابطے کی کوشش کی تھی، وہ سب یاد رہ جانے والا تھا، پھر یوں ہوا کہ ذرا دیر پہلے جس شخص کو عرش صاحب سے چھیڑ کرتے ہوئے دیکھ کر ہم اُلجھ رہے تھے، اُسے اب یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو جیسے اس شخصیت کی کایا کلپ ہوگئی اور عالی صاحب کا ایک اور ہی روپ سامنے آیا، جس کا نقش حافظے پر ہمیشہ کے لیے مرتسم ہوگیا۔
سچی بات یہ ہے کہ ایک اسی واقعے پر موقوف نہیں، بعد ازاں انھیں اسی طرح انسانی اخلاص سے کچھ اور لوگوں کے کام آتے بھی دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ مدد اور تعاون کے معاملے میں بے حد عملی انسان تھے اور نہایت کشادہ دل اور وسیع ظرف رکھتے تھے۔
عالی صاحب کی زیادہ شہرت شاعر کی حیثیت سے ہوئی بالخصوص ان کے ملّی، قومی نغموں اور دوہوں کی نسبت سے۔ ویسے انھوں نے نہایت عمدہ سفرنامے لکھے اور شخصی مضامین یا خاکے بھی قلم بند کیے جو بلاشبہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاعری میں بھی عالی صاحب نے غزل میں یادگار شعر کہے ہیں۔
اس کے علاوہ ہمارے یہاں جن شاعروں نے سائنسی موضوعات کو انسانی احساس سے آمیز کرکے نظمیں کہیں، ان میں بھی وہ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی طویل نظم ’’انسان‘‘ اردو نظم کی تاریخ کا ایک اور غور طلب باب ہے۔ غزل کے چند اشعار:
یہ احترامِ تعلق یہ احتیاط تو دیکھ
کہ زندگی کو کبھی ہم نے رائگاں نہ کہا
———
کہیں تو ہوگی ملاقات اے چمن آرا
کہ میں بھی ہوں تری خوشبو کی طرح آوارہ
———
کچھ نہ تھا یاد بجز کارِ محبت اک عمر
وہ جو بگڑا ہے تو اب کام کئی یاد آئے
———
میں ایک جان ہوں کب تک ہزار سمت کھنچوں
اب آئے موت گلے سے لگائے ماں کی طرح
ان کے ملّی نغموں کی بھی ہمارے یہاں بڑی گونج رہی۔ ’’ہم تابہ ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفوی، مصطفوی، مصطفوی ہیں‘‘، ’’جیوے جیوے پاکستان‘‘، ’’سوہنی دھرتی ﷲ رکھے قدم قدم آباد تجھے‘‘ تو وہ نغمے ہیں جو ایک زمانے میں کتنی ہی زبانوں پر مہکتے دکھائی دیتے تھے۔
آج پلٹ کر دیکھیے تو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے گزشتہ برس جیسے کسی طلسم کدے میں گزرے تھے جہاں یادگارِ زمانہ لوگوں کو دیکھنے، سننے اور ان کی صحبتیں اٹھانے کا موقع ملا۔
عجیب لوگ تھے وہ اور عجب طرزِ زندگی تھا جس کی اس دور میں کہیں کوئی پرچھائیں تک دکھائی نہیں دیتی۔ یہ لوگ کیا تھے جیسے روشنی بکھیرتی زندہ آوازیں تھیں جن کی گونج آج بھی دل و جاں میں سنائی دیتی ہیں۔
دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا
وہ تری یاد تھی اب یاد آیا
آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست
تو مصیبت میں عجب یاد آیا
دن گزارا تھا بڑی مشکل سے
پھر ترا وعدۂ شب یاد آیا
تیرا بھولا ہوا پیمان وفا
مر رہیں گے اگر اب یاد آیا
پھر کئی لوگ نظر سے گزرے
پھر کوئی شہر طرب یاد آیا
حال دل ہم بھی سناتے لیکن
جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا
بیٹھ کر سایۂ گل میں ناصرؔ
ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا
کوئی تو شکل محبت میں سازگار آئے
ہنسی نہیں ہے تو رونے سے ہی قرار آئے
ہے ایک نعمت عظمیٰ غم محبت بھی
مگر یہ شرط کہ انساں کو سازگار آئے
جنون دشت پسندی بتائے دیتا ہے
گزارنی تھی جو گھر میں وہ ہم گزار آئے
گزارنی ہے مجھے عمر تیرے قدموں میں
مجھے نہ کیوں ترے وعدوں پہ اعتبار آئے
تمہاری بزم سے آکر وہی خیال رہا
ہم ایک بار گئے تم ہزار بار آئے
نگاہ دوست کوئی اور بات ہے ورنہ
تو بے قرار کرے اور مجھے قرار آئے
ہے مطمئن بھی تو کس کس امید و بیم کے ساتھ
وہ نا مراد جسے لطف انتظار آئے
بتا گئی ہے جو مجھ کو وہ بے قرار نگاہ
نہ کہہ سکوں گا اگر آج بھی قرار آئے
یہ امتیاز ہے غالبؔ کے بعد عالیؔ کا
کہ جس پہ آپ مرے ہیں اسے بھی مار آئے