
-
فرمان الہی
-
نماز کے اوقات
- جمعرات 22؍ رمضان المبارک 1447ھ12؍مارچ 2026ء
- بانی: میرخلیل الرحمٰن
- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

 فرمان الہی
فرمان الہی
 نماز کے اوقات
نماز کے اوقات


برصغیر میں شاعری کو تہذیب کا نمائندہ ہمیشہ کہا گیا۔ اُردو اور خاص کر اُردو شاعری نے شہنشاہوں سے لے کر درویشوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ گدڑی سے لے کر تخت طائوس تک سب صفوں میں شاعری نے سربراہی کی۔ زبانوں کو رشتوں میں بھی اُردو شاعری نے سمیٹا اور انگریزوں کے ہاتھوں تہذیب کے زوال کو نظیر اکبر آبادی سے سودا، میر اور غالب نے شہر آشوب کے توسط، داستان ہزیمت لکھی۔
انگریزوں نے جاتے ہوئے، قائداعظم کی توقعات کے برعکس تقسیم ہندوستان کے لئے یہ زہریلی لکیر پھیری۔ قائداعظم نے اس زخم کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور آزادی کو ابتدائے سفر کی طرح قبول کیا۔ قائداعظم اور مہاتما گاندھی نہیں جانتے تھے کہ یہ خوں آشام تقسیم لاکھوں کے خون اور ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کے ساتھ، انسانیت کی بنیادیں ہلا دے گی۔ اس لئے احمد راہی اور امرتا پریتم نے پنجابی اور فیض صاحب نے کہا ’’یہ داغ داغ اُجالا، یہ شب گزیدہ سحر‘‘۔ اُردو شاعری نے ایک ہزار میل کے فاصلے کو بھی شاعری کے ذریعہ ہی مختصر کیا، نذرالاسلام اور علّامہ اقبال قومی شاعر مانے گئے اور مشاعروں کی تہذیب نے قریہ قریہ شاموں کو آباد کیا۔
قیام پاکستان سے پہلے ہی ترقّی پسند تحریک نے، برصغیر کی آزادی اور قیام پاکستان کے جذبے کو مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ، قدم بہ قدم آگے بڑھایا۔ جوش صاحب اُسی زمانے میں شاعرِ انقلاب اور حفیظ جالندھری شاعرِ شاہنامۂ اسلام، مشہور ہو چکے تھے۔ اُدھر اختر شیرانی کی عشقیہ شاعری نے اپنی اور بعد کی نسل میں غزل کی وہ خو بو بوئی کہ اب غزل میں غم عشق کے علاوہ غم زمانہ اور ہجرتوں کی یادوں کو ناصر کاظمی، احمد مشتاق اور منیر نیازی، اوائل شباب سے اُداسی کو گھر کی دیواروں پر سوتا ہوا دکھایا اور اور منیر نیازی نے خان پور کو یاد کیا، احمد مشتاق نے کہا ’’یہ دریا خامشی سے بہہ رہا ہے۔ اُسے دیکھیں کہ اس میں ڈُوب جائیں‘‘
غزل کے علاوہ نظم معریٰ نے بھی جب مجاز اور فیض کے علاوہ علی سردار جعفری اور احمد ندیم قاسمی کا ہاتھ پکڑا تو پڑھنے والے نوجوانوں نے اُمیدِ سحر اور نئی صبح جیسی تازگی کی شکل میں نظم و غزل کی مرّوجہ روش اور لغت میں نئے موضوعات کو مشقِ سخن میں شامل کیا۔ میراجی نے مشرق و مغرب کے نغمے ترجمہ کیے تو نوجوان نسل نے روسی اَدب کا ذائقہ بھی چکھا۔ ترجمے بھی کیے، پڑھے اور انقلاب کی لہر کو، ن۔م۔راشد نے جس اُسلوب میں متعارف کروایا، وہ نئے شاعروں میں اس لئے مقبول ہوا کہ راشد صاحب نے فارسی اور اُردو کے امتزاج کو جیسے برتا۔
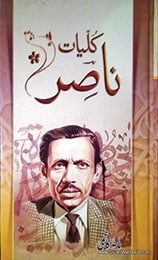
وہ نظم میں، عالمی سطح کے مضامین کو بھی، ابولہب کی دُلہن جو آئی، جیسی نظم کے ذریعہ، توجہ دلائی کہ بس وہی لکھنوی یا علی گڑھ کی تہذیب کو یاد کرنا لاحاصلی کا دریا ہے۔ ’’آنکھیں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا‘‘۔ جیسے مصرعوں نے زمینی حقائق کو شاعری کا پیرہن دیا۔ اب جبکہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں زمینی فاصلہ پیر کی زنجیر بن گیا، بنگال کے قحط کو یاد کرنے والوں نے کبھی برملا اور کبھی نصاب میں، حکمران جنتا سے سوال کرنے، مساوی حقوق مانگنے اور معاشی بحران کے استبداد سے نکلنے کے لئے عوامی سطح پر جدوجہد شروع کی۔
اِدھر مغربی پاکستان میں بغیر آئین کے آتی جاتی حکومتوں کو، فوج نے سرحدوں کے علاوہ ملکی سیاست کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آمریت کے اس طوق کو حبیب جالب نے للکارا، آمریت اور بائیس خاندانوں کی حاکمیت اور عوام کی بے بسی کو محترمہ فاطمہ جناح کے عوامی جلسوں میں حبیب جالب ایک وہی لہر لے کر اُٹھا جو مجاز نے خاتون کے حوالے سے انقلابی نظم پڑھی تھی۔ کہا ’’تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا‘‘۔
آمریت کا عمامہ اُترا تو سب سے تیز اثر بنگالیوں پر ہوا۔ الیکشن میں بنگالی آگے نکل گئے اور وہ لمحہ بھی ہماری تاریخ کا سیاہ باب بنا کہ جس دن پاکستان دو لخت ہوا۔ اس کے بعد نفرتوں کے ریلے نے بنگالیوں کو اس طرح قابو کیا کہ ہر آنے والی حکومت، پاکستان سے مخاصمت کا جھنڈا اُٹھائے آگے چلتی رہی۔ ہرچند فیض صاحب نے کہا ’’خون کے دھبّے دُھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد‘‘ ناصر کاظمی نے کہا ’’وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے۔ بس رہ گیا افسوس ہی افسوس‘‘۔
زمانہ کبھی ٹھہرا نہیں رہتا۔ بھٹیالی گانے والے الگ ملک بنا بیٹھے اور ہم نے پہلی دفعہ سرکاری اور عوامی سطح پر یوم مئی منایا کہ جس میں اقبال بانو نے ’’لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے‘‘ فیض کی نظم کو دوام بخشا۔ عورت اور مرد کی مساوات قائم کرنے کے لئے، بھٹو صاحب اور بیگم بھٹو دونوں نکلے مگر بھٹو کی شعلگی نے تعلیمی اور صنعتی اداروں کی قومیانے کی پالیسی نے چاروں جانب قیامت کا دھچکہ لگایا۔ سیاسی میدان میں ان کی تنہائی کو ضیاء الحق نے کیش کرتے ہوئے شدید زباں بندی اور تحریر کو سنسر کی نظر کیا۔ نظم کا یہ حصار 11برس تک قائم رہا۔ بہت سے لکھنے والے پابۂ زنجیر ہوئے۔
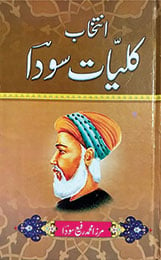
خود بھٹو صاحب مصلوب ہوئے۔ کون لکھنے والا تھا کہ فہمیدہ ریاض سے لے کر احمد فراز، افتخار عارف، پروین شاکر، سلیم شاہد اور جمال احسانی نے احتجاجی شاعری کو فروغ دیا۔ وہ سلسلہ نوجوان نسل تک غالب ہے کہ سیاست میں کوئی دیدہ وری نہیں آئی۔ نوجوانوں نے کھل کر لکھا کہ ’’فٹ پاتھ میں مت چلنا وہاں تو مزدور کے خواب پڑے ہوئے ہیں‘‘۔ اس زمانے میں ہر افسانہ اور ہر شعر سنسر کیا جاتا اور کتابیں بین کی جاتیں۔
درِ زندان بار بار کھلتا، بار بار کوڑے منہ کے سامنے مائیک رکھ کر لگائے جاتے، قلعہ لاہور کی کال کوٹھریوں میں بڑی رونق رہی۔ بیڑیاں اور زنجیریں کھنکتی رہیں۔ آمریت کبھی کالاکوٹ پہنتی اور کبھی خاکی پینٹ، زباں بندیوں کی رسم جاری رہی۔ بے غیرتی نے سونے کا لبادہ پہن لیا۔ آنکھوں میں حیا کی رسم ختم ہوگئی۔
شاعری نے اب دو پیرہن بدلے۔ کچھ لکھنے والوں نے نعتیہ تغزل میں حفیظ تائب اور مظفر وارثی کی طرح خدا اور اس کے رسول سے شکوے کیے اور کچھ نہیں بہت سے شاعروں نے مرثیہ کے انداز میں احوال حال اور احوال وطن لکھا اور اب تک لکھ رہے ہیں۔
یوں تو دُوسری جنگ عظیم کے دوران، انگریزوں نے فوجی ترانے لکھوانے کی رسم ڈالی تھی۔ حفیظ جالندھری نے لکھا تھا ’’میں تو چھورے کو بھرتی کرا آئی رے‘‘۔ یہی چلن انڈیا۔ پاکستان کی دونوں جنگوں کے دوران، جنگی ترانے، اچھے بُرے سبھی لکھے گئے۔ پنجابی میں تو رشید انور نے لکھا ’’جنگ کھیڈ نئیں ہوندی زنانیاں دی‘‘۔ ہر دفعہ جب طبل جنگ بجتا ہے۔ ’’وقت شہادت آیا ہے‘‘ سارے میڈیا پر گونجنے لگتا ہے۔ جنگ کی شعلہ ریزی کبھی افغانستان، کبھی وزیرستان، کبھی فلسطین اور کبھی یوکرین میں انسانیت کو بھسم کرتی ہے۔
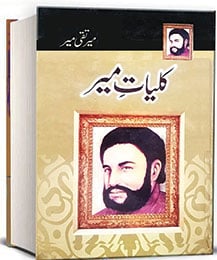
کشمیر اُداس ہے لکھو کہ ’’وطن ہمارا، آزاد کشمیر‘‘ ساری دُنیا میں، فنڈز، تعلیم و صحت کے لئے نہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کے نام پر قرضوں پر قرضہ لینے کے لئے، معاشی جبر کی ریکھائیں کھل گئی ہیں۔ امن کی دُہائی دیتے دیتے لوممبا، منڈیلا، ایڈورڈ سہتو دُنیا سے چلے گئے۔ نوم چومسکی ہو کہ لیلیٰ خالد، ڈاکٹر مبارک، دھتی رائے، ڈاکٹر جعفر احمد ، پرویز ہود بھائی نے جہاد کے نام پر ہندوتوا کے نام اور یہودی آبادکاری کے نام پر انسانیت کا قتل اتنا بڑھایا کہ ہر امریکی نوجوان ہنس کھیل کے کسی مسجد، کسی تھیٹر، کسی کیفے اور کسی چرچ میں گولیاں چلا کر خود کو بھی ڈر کے مار لیتا ہے۔
فیض صاحب، احمد فراز، حبیب جالب، جوہر میر، فارغ بخاری، ضیاء الحق کی ستم رانیوں سے تنگ آ کر پردیس سدھارے۔ ’’مرے دل مرے مسافر‘‘ جیسی نظمیں۔ احمد فراز اور حبیب جالب نے دانشوروں کو مخاطب کرتے ہوئے للکارا کہ اس اَدب کی بے توقیری کے زمانے میں کاسۂ گدائی لئے، اپنی تخلیقات ان رسالداروں کو مت پیش کریں کہ جن کے ہاتھ خون میں رنگے تھے۔ اس زمانے میں ’’احتساب‘‘ نام کے پرچے میں انقلابی تخلیقات شائع ہوئیں۔ سلیم شاہد نے خوشبو کی شہادت کے نام سے، بھٹو کی پھانسی کو دل گداز کرنے والی تحریروں کو مرتب کیا۔ سزا کے طور پر جیل بھی کاٹی اور حسن عباس رضا نے بھی حزنیہ نظموں کا مجموعہ شائع کیا۔ وہ بھی لائق سزا ٹھہرا۔ صحافیوں کو بھی بولنے کی پاداش میں کوڑے کھانے پڑے۔

اِسی سنسنرشپ سے اُکتا کر، دانشوروں اور شاعروں نے ترجمے کرنے شروع کیے۔ دُوسری جنگ عظیم کے بعد جو اَدب تحریر ہوا، وہ سب ہم نے ترجموں کے ذریعہ پوری دُنیا میں پھیلایا۔ اس سلسلے میں ہمارے ادیب جرمنی میں منیر احمد، لندن میں ساقی فاروقی اور کینیڈا میں اشفاق حسین نے خود بھی لکھا اور ترجموں کے ذریعہ ناظم حکمت، محمود درویش سے پاکستانی اَدب منو بھائی آشنا ہوا، منو بھائی بھی ترجمے کرتا رہا۔ ان تراجم نے مزاحمتی کی تحریک کو جلا بخشی۔
اقبال ساجد نے پاکستان میں پھیلتے بھوک کے سایوں کو شاعری میں سمویا اور سلیم شاہد نے بتا دیا کہ ’’باہر جو میں نکلوں تو برہنہ نظر آئوں۔ بیٹھا ہوں میں گھر میں در و دیوار پہن کر‘‘۔ اختر حسین جعفری نے سروں پہ دوپٹے اوڑھے بین کرتی خواتین کے بیان کو حزنیہ رنگ دیا۔ نئے شاعروں نے شاید سارا شہر بچایا جا سکتا تھا۔ جدید لہجے دے اور یاد کرایا کہ ایک زمانہ تھا جب چاند میں بھی روٹیاں نظر آتی تھیں۔ اب وہی زمانہ عود کر آیا ہے۔
اُردو نظم نے عسکریت پسندی کو بالکل قبول نہیں کیا کہ ہماری تہذیب و ثقافت میں، صوفی شعرا کی بازگشت زمانے کو سمجھاتی رہی کہ صرف نہانے دھونے سے مذہب، خدا اور امن نہیں ملتا۔ ایسا ہوتا تو مچھلیاں اور پانی کے تمام حشرات الارض ہی ارفع درجے پر موجود ہوتے، سارے صوفی شعراء نے انسانیت اور زمین سے محبت کی تلقین کی۔ غزل جس کو غالب ، سراج اورنگ آبادی، میر، سودا اور مصحفی نے اسلوب اور اظہار میں خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں بیان کیا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو بارہا یاد دلایا کہ ’’ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے‘‘۔ ہمارے چھوٹے شہروں میں شاعری میں بہت نئے تصوّرات شامل کئے گئے۔

راشد صاحب کی نظم نے مبارک احمد، افتخار جالب اور قمر جمیل کو نئے اُسلوب کی طرف راغب ہونے کے لئے اُکسایا کہ گل و بلبل کی شاعری، مردانہ وجاہت اور عورت کے سراپے میں سنجیدگی کو تمسخر کی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ اگرچہ حالی کے زمانے سے نئی لفظیات کی طرح پڑ چکی تھی۔ سجاد ظہیر کی نظموں میں ’’پگھلا نیلم‘‘ کے ذریعہ وہ شاعری وجود میں آئی جو بحر اور قافیے کی پابندیوں سے آزاد، نظم کو وہ وجود دے رہی تھی، جہاں مختصر افسانہ بھی نہیں پہنچا تھا۔ 1962-70ء میں لکھنے والوں نے اس تجربے کو قبول کرتے ہوئے صرف موضوعات میں تنوع لانے کی کوشش نہیں کی بلکہ غزل اور نظم اپنے انداز میں چلتے رہنے دیا۔
گریز کیا روایتی لغت، جام و مینا کی صراحی اور میخانے کی تکرار کو خود راشد صاحب نے نثری نظم کے تجربوں کو جلا بخشی۔ احمد ہمیش، ثروت حسین، افضال سیّد، عبدالرشید، افتخار جالب، انیس ناگی اور جیلانی کامران نے نثری نظمیں لکھنے کا ڈول ڈالا۔ ہونٹوں کو گلاب کی پتی کہنا تسلیم، مگر ان ہونٹوں کو بولنے اور مدعا کیا ہے۔ بیان کرنے کے لئے اُردو اَدب کے کینوس پر مرد لکھنے والوں کے قبیلے میں خواتین نے اوڑھنی کے رنگ بھی بتائے اور بتایا ’’گھر کے اندر کاٹنی ہے تیرگی۔
گھر سے باہر رہ کے بھی ڈرنا بہت‘‘۔ فہمیدہ ریاض نے باکرہ خاتون کا احوال لکھا تو پروین شاکر نے نوجوانی کے نوخیز جذبوں کو زباں بخشی۔ اس نے اپنا سفر زندگی، نوکری اور شادی کے تجربات کی گہرائی میں گئی۔ منصبِ دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا جیسے شگفتہ مصرعے اُردو شاعری کو عطا کئے۔ پروین کی اچانک موت نے صدمے کے عالم سے تنویر انجم، عشرت آفریں، عذرا عباس اور فاطمہ حسن نے اپنے قبیلے کو وسعت بیان دی۔
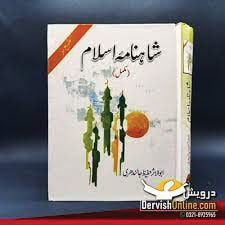
جس طرح اُردو غزل کی بے احتیاطی، زودگوئی اور بلاسبب قافیہ پیمائی نے ، بنیادی مبادیات کو دُھندلا دیا خورشید رضوی، افتخار عارف، مصطفیٰ زیدی اور عباس تابش نے بہت سنبھالا دیا، مگر مشاعروں نے اور وہ بھی شہر شہر بے سروپا انڈیا اور پاکستان کے مشاعرے سم قاتل بنے۔ پھر یاد آنے لگے ناصر کاظمی، منیر نیازی اور پرانا ظفر اقبال۔ اگرچہ چھوٹے شہروں میں اب بھی غزل اور اچھی لکھی جا رہی ہے۔ دامن تار تار نہیں ہے سبب وہی کہ فارسی نابلد قوم کی شعری کینوس اور پھر کلاسیک سے سیکھنے کا شوق کم اور میڈیا کے ذریعہ خاص کر سوشل میڈیا کو اَدب کی منتہا سمجھنے والے، اپنی ڈگر پر رواں ہیں۔ غزل اور اچھی غزل لکھنے والے ضعیف اضافتیں بے معنی ترکیبیں دوسروں سے مستعار لے کر شبِ فراق کو رگیدنا، سخن بنانے والوں کی بھیڑ تو پیدا کرتا ہے۔ مگر وہ جسے احمد ندیم قاسمی صاحب ’’معیار‘‘ لکھتے تھے۔ وہ عنقا ہے۔
نظم میں بھی کھوکھلی تجریدیت اور موضوع سخن کی کمیابی اور نایابی اس لئے بھی ہے کہ جب کورونا کی تکلیف، ہجرت کا دُکھ، بے زمینی کے ماحول میں کھلے آسمان تلے پلتے بچے، بلبلاتی مائیں اور بھوک میں چوری بھی جائز ہو جائے تو پھر جذبے اپنی لغت ساتھ لاتے ہیں۔ ساری دُنیا میں بے مقصد پھیلی جنگیں، بڑی طاقتوں کا بے شمار اسلحہ فروخت کرنے کے لئے، چھوٹے اور معاشی کمزور ملکوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے حربوں کو نظرانداز کرنا۔ ان کا بیان ہی تو شیوتو شنکا ، پابلو نرودا، مایا انجلو، توفیق زیاد، محمود درویش اور مارگریٹ ایٹ ووڈ بنانا ہے۔ شمالی وزیرستان سے بلوچستان اور افغانستان تک وبا کی طرح پھیلی خوں ریزی نے ہمارے نظم کو حضرات کو بھی عسکریت پسند بنا دیا۔ دوسری طرف دُنیا بھر میں طالبانیت، ہماری قومی معاشرت کو زمین سے اُٹھتی اور لپٹتی تہذیب کو رعونت، غیرت کے نام پر قتل کے ساتھ عورت کے جسم کی بے حرمتی اور ان پر پورنو فلمیں بنانے کی بے حیائی، اگر غالب ہو تو مانگے تانگے کے تصوّرات مرکز سے دُوری کی نشاندہی کرتے ہیں۔

جب تاریکی فضا اور آسمان میں بھی ہو تو کہیں ایک آدھ ٹمٹماتے ستارے کو اچھا کہا جاتا ہے۔ مسکراہٹ عطا کرنے والا سمجھ کر، جب قومی شاعری پر نظر ڈالیں تو سچ یہ ہے کہ ہماری قومی زبانوں میں لکھے گئے اور پسماندہ علاقوں سے اُٹھتی آوازیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ عشق کی پس پائی ہے کہ معاشی کجروی، بے حسی، اخلاقی بے راہ روی اور علم و تہذیب کو گئے زمانوں کا پیرہن سمجھ کر، اپنے اُوپر رومانویت طاری کرنے سے ’’جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے‘‘۔ ایسے مصرعے صرف زبان دانی یا فارسی آ جانے سے نہیں نازل ہوتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روز شام کو دو غزلیں یا دو نظمیں لکھنا اپنے اوپر فرض کر لیا جائے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح زہرہ نگاہ کا اُسلوب اور نظم کا پیرایہ ماحول کے ساتھ بدلا ہے۔ وہ ایسی نظمیں لندن میں بیٹھ کر نہیں لکھ سکتی تھیں۔
ہم جنسیت ایسا موضوع ہے جس کو مردوں اور عورتوں، دونوں میں پایا جاتا ہے مگر افسانے اور ناول میں تو ہمارے اَدب میں جگہ پائی ہے۔ دُنیا بھر میں، تمام ملکوں کی نوجوان نسل، جسے ہم بے راہ روی سمجھتے ہیں۔ پر وہ ایک حقیقت ہے۔ ہماری اُردو نظم میں خاص طور پر افتخار نسیم نے شکاگو میں بیٹھ کر اس موضوع کو اپنایا کہ وہ خود ایسا تھا۔ اس کی نظموں کی کتاب ہمارے اپنے وطن میں نہیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہیں ہیں۔
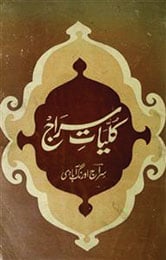
افتخار نسیم کے علاوہ تیسری جنس کے حوالے سے ساقی فاروقی نے بھی نظم لکھی تھی مگر اس شخص کی دہری شخصیت، اُلجھائو اور بدن میں تبدیلیوں کو نوٹ کرنا اور بیان کرنا، ہماری لغت، اُسلوب اور پیرایۂ اظہار میں موجود نہیں۔ ہماری نئی فلموں میں ایسی شخصیت کو مثبت وجود کی صورت اور کہیں کہیں اندرونی خلفشار کو تصویری شکل اور لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس موضوع کے بہت سے پہلو ہیں، مثلاً ایسے اشخاص سے دوستیاں رکھنا یا معاشرتی زندگی میں برابر کی سطح پر جگہ دینی، اس میں خانگی ماحول سے سوسائٹی کا ردعمل بھی زندگی پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ فہمیدہ ریاض نے جنس کے سلسلے میں مردانہ رعونت کو شاعری میں پیش کیا ہے۔
اَدب و شاعری میں بیوہ عورت کو بھی قابل رحم سمجھنے کی جیسی کلاسیکی روایات تھیں، اس سے سرِمُو انحراف نہیں کیا گیا۔ مولانا حالی سے احسان دانش تک بیوہ پر نوحہ کناں رہے۔ کہانیوں اور ناول میں بھی اس کی آنے والی زندگی کی پیچیدگیوں کو روایت سمجھ کر بیان کیا ہے۔ عورت چاہے بیوہ ہو کہ بیاہی اُسے شخص سمجھنے، گھر میں سجاوٹ کی چیز کے علاوہ، مزاحیہ شاعری نے ہر طرح کی کسر پوری کر دی ہے۔ اسی طرح جن بچیوں کی شادی نہ ہو سکی یا طلاق ہوگئی اوروہ خود کو کارآمد سمجھتے ہوئے، کچھ کرنا چاہیں تو گھر اور باہر، سرِ راہ کتنے مسائل، کبھی گیدڑ بھبکیوں کی شکل میں اور کبھی بھوکے شیر کی طرح منہ کھولے اژدہے کی طرح دیکھتے، ملتے اور سلوک کرتے معاشرے میں شاعری کی صنف پاس سے گزرتی رہی ہے۔ شاعری میں فعال اور مصروف وہ عورت بھی بیان پائے، جسے ابھی تک بلاسوچے سمجھے شمع محفل گردانا جاتا رہا ہے۔
بڑھاپے اور اس میں مالی اور سماجی تنہائی، موت کی طرح وہ اَٹل حقیقت ہیں جن کو پوری دُنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص وہ والدین جو بچوں کی ہجرت کر جانے یا شادیوں کے بعد اپنے مسائل سے آگے سوچتے ہی نہیں۔ پھر یہ داستانیں بھی عام ہیں کہ جائیداد کے حصول کے لئے والدین کو مار دینا ہی اور ملک سے باہر نکل جانا ہی، آئے دن کا معاملہ ہے۔ اُردو شاعری میں تو ڈاکٹر وحید نے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ قومی زبانوں کے کلاسیکی اور جدید اَدب میں بھی یہ حوالے اس لئے بھی نظر آتے ہیں کہ یہ زبانیں، تہذیب سے جُڑی ہوتی ہیں۔
فیض صاحب نے اُردو شاعری میں جدید نظم میں ’’سو کر ہی نہ اُٹھیں یہ ارادہ تو نہیں تھا‘‘ بڑھاپے اور موت کے مشترکہ تجربے کو ملال کی شکل میں نہیں، حقیقت کے طور پر پیش کیاہے۔ موت کے موضوع پر نوحہ گری بہت ہے۔ اسی نوحہ گری کی جڑیں مرثیہ گوئی کی دیگر اصناف میں بہت گہری ہیں۔ نو تصنیف مرثیہ پڑھنے کی روایت ساری دُنیا میں ابھی تک قائم ہے۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ اب کوئی انیس کی طرح یہ نہیں لکھتا کہ ’’کھا کھا کے اوس اور بھی سبزا ہرا ہوا‘‘ بلکہ حسین کے غم میں دُنیا اور اپنے غم اور وطن پہ آفات کا تذکرہ بھی بیان پاتا ہے۔ اسی طرح نعتوں میں بھی وسعتِ بیان نظر آتی ہے۔
نظم اور خاص کر نثری نظم نے زمانے بھر کے غم اور اک ترا غم بھی شامل کیا ہے۔ اس کے آثار تو دُوسری جنگ عظیم کے بعد ہی ظاہر ہونا شروع ہوگئے تھے جس میں گھروں کا اُجڑنا، اپنے ملک سے زبردستی ہجرت پر مجبور کیا جانا، بے گھری خانماں بربادی کی یہ داستان عالمی اَدب کا معتدبہ حصہ ہے بلکہ واقعات نگاری میں مجموعی طور پر نثری نظم حاوی رہی ہے۔ اسی طرح ظاہری شان و شوکت کا ملمع اُتارنے کا فریضہ نثری نظم نے ادا کیا ہے۔
ویسے تو کلاسیک میں زندگی کو بھی قفس کہا گیا ہے مگر سیاسی قید، برصغیر میں انگریزوں کے دور میں اذیتوں کا باب ہے۔ پاکستان بنتے ہی پنڈی سازش کیس سے لے کر آج تک دراصل سیاست اور دانشوری دونوں میں حبسیہ داستانیں ہی ملیں گی۔ ’’درِ قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے، تو فیض دل میں سہارے اُترنے لگتے ہیں‘‘۔ یہ اندازِ شعر منفرد ہے۔ ’’آج تک بوئے سخن آتی ہے، دیواروں سے ایسے بولتے مصرعے، تمام حبسیہ شاعری میں ملیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لہجے کی تمام شاعری کو حبسیہ کیوں گردان رہی ہوں۔
75برس سے ہمارے سیاسی اور معاشرتی ماحول میں ہر سطح پر زباں بندی کا دور دورہ ہے۔ ہرچند وہ زمانے جس میں ہر تحریر باقاعدہ سینسر ہوتی تھی۔ اس کے نتیجے میں دوطریق اظہار نے جگہ لی۔ ایک تو ہر لکھنے والے کے دماغ میں ایک سپاہی بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ خود ہی قلم پکڑتے اور لکھتے ہوئے محتاط ہوتا ہے اور دوسرے ہر طرح کے لکھنے والے، جن کو موجود سرکار، باغی اور غدار سمجھ کر کبھی لاپتہ، کبھی زبردستی اپنے ہی ہم وطنوں کو ڈی پورٹ کر دیتی ہے۔ اس طریق سیاست میں جمہوریت کا لفظ بے معنی ہو جاتا ہے۔ شاعروں نے یہ موضوع برتا۔
قیمینزم کا نام اُردو شاعری میں بعد میں، اس سے پہلے ادا جعفری، زہرہ نگاہ کے شعری منظر سے یکدم غائب ہونے پر، اگلی صبح نیا سُورج تلاش لائی کہ اب مختلف لغت اور عنوانات نے شعری پیرہن پہننے کے بعد، بقول شمس الرحمان فاروقی ’’تانیث‘‘ نے اپنے پیر جمائے، کلاسیکیت غزل اور نظم میں لانے والوں کو گراں گزرا، مگر ملک میں بڑھتے ہوئے مولویانہ اثرات کے مقابل خواتین کی عملی سرگرمی اور شاعری نے بہت سے حجابات توڑ دیئے۔ بقول انتظار حسین، اس مذہبی بے اعتباری کے موسم میں گزشتہ چالیس سال سے اَدبی اور تحریکی تسلسل کے ساتھ خواتین لکھ رہی ہیں اور لڑ رہی ہیں۔ تنویر انجم اور عشرت آفریں کے یہاں موضوعات کی فراوانی ہے۔
طوائف کے کردار کوفکشن اور ناول میں امرائو جان اور وزیر بیگم کے نام کے ناولوں میں کہیں ان کی فنّی استعداد تو کہیں پیشہ ورانہ بازاری پن یہ اچھا، بُرا، سب کچھ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے۔ البتہ پچاس برس پہلے قتیل شفائی نے باقاعدہ ایک شعری مجموعے کا نام ہی طوائف رکھا تھا۔ وہ الگ کہانی ہے۔
خودکشی کا موضوع، اصل واقعات اور شاعری کے تنوع اور تلمیحات میں بہت آیا ہے۔ مگر گزشتہ 60 سالوں میں ممتاز شاعروں نے خودکشی کی ان کے مرنے کے بعد، ان کے اشعار میں حوالے تلاش کئے گئے۔ مثلاً مصطفیٰ زیدی آج تک نہیں معلوم کہ اسکو ڈرگز پلائی گئیں کہ اس نے اپنے آپ ہی خودکشی کی۔ شکیب جلالی، اچھا شاعر، ذہنی طور پر معقول نظر آتا تھا۔ اچانک خودکشی کی خبر آئی۔ ثروت حسین نے خود بتایا تھاکہ اُسے ریل کی پٹریاں بہت ہانٹ کرتی تھیں۔
ایک دفعہ خودکشی کی کوشش ناکام ہوئی مگر دُوسری دفعہ ، اتنا انوکھا شاعر چلا گیا، ڈرگز اورڈرنکز کے اُلٹے سیدھے ملاپ کے باعث، سارہ شگفتہ، بھی ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کی۔ البتہ ساغر صدیقی، صغیر ملال اور اقبال ساجد نے کچی شراب سے خود کو تباہ کیا۔ ذی شان ساحل، نثری نظم کا بے پناہ شاعر، اس کی معذوری نے شاعری اور فطرت میں اتنی معصوم نظمیں لکھیں کہ اب جبکہ وہ اور اکبر معصوم نہیں تو پڑھنے والے، ان دونوں کو یاد کرتے ہیں۔
آج کی شاعری میں وہ کلاسیکی پیکر تراشی، چشم و اَبرو اورمیخانے کا تذکرہ خال خال ہے، یہ نہیں کہ شاعر بہت پاک باز ہوگئے ہیں، بلکہ ذاتی اور زمانے کے بوجھ کا بیان شاعری میں نمایاں ہے۔ گزشتہ چالیس سال سے جب سے افغانستان پھر عراق اور امریکہ کی زبردستی جنگ پروری نے، ہماری صدیوں پرانی ثقافتوں کو نابود کیا۔ اپنا اسلحہ فروخت کرنے کے لئے، اسلامی ممالک کو منڈی بنایا۔ ان سارے ملکوں میں سوائے خونریزی اورشکست کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔
مگر ہم شاعری میں کشمیر،فلسطینی، کالے امریکی اور جنوبی امریکہ کے شاعروں کے قریب ہوگئے کہ شاعری میں مہاجرت، بے گھری، نفرتوں کےا یسے بیچ بوئے گئے کہ بیشتر موضوعات میں تلخیاں چہرہ بدل بدل کے سامنے آنے لگیں۔ حبیب جالب سے سیاست اور اس کے پیش کاروں کی قریب اور دوغلے پن کو ایسے پیش کیا کہ آج تک سچ ہے۔ پہلے غزل کی زمین کو آسمان اورعشق میں تلاش کیا جاتا تھا۔ گو اب بھی ماضی پرست، غزل کے علاوہ نظم اور نثری نظم کو زِک پہنچا رہے ہیں۔ مگر ایسا تو ہر زمانے میں ہوا۔ زاہد ڈار، احمد ہمیش، افضال سیّد، عبدالرشید، نثری نظم کے اہم نام ہیں۔
شاعری میں جاپانی شاعری کی ہیئت کو پسند کرتے ہوئے بہت سے شاعروں نے ہائیکو اور ثلاثی لکھے۔ مجموعے بھی حمایت علی شاعر اور دیگر شعرا کے سامنے آئے۔ اس طرح مسلسل غزل کے مجموعے عدیم ہاشمی اور صابر ظفر سامنے لائے۔ مضمون آفرینی کے ساتھ کہیں کہیں نئے استعارے چھلکتے ہیں۔
نجم حسین سیّد، سرمد صہبائی اورقومی زبانوں کے شاعروں نے بھی ہیئت کے تجربے کئے ہیں۔ ماہیے، گیت، رُباعیات اور انیس ناگی کی طرح نثری نظم، پیراگراف کی شکل میں لکھے۔ البتہ اسد عمر خان نے پرانے گیت کا مصرعہ انوکھا لاڈلا، کھیلن کو مانگے چاند، کو گیت میں ایسا پرویا کہ سارے عالم میں یہ مصرعہ ان سے ہی منسوب رہا۔
قومی، وطن سے محبت اور افواج پاکستان کی محبت کو دونوں جنگوں میں صوفی صاحب کے گیت اور نورجہاں کی آواز اَمر ہوگئے اس طرح دیگر قومی دنوں کے حوالے سے شاعروں نے فرمائشی دیوان کے دیوان لکھ دیئے۔ اس میں جمیل الدین عالی نے جیوے پاکستان اور مسرور انور نے سوہنی دھرتی اللہ رکھے جیسے نغموں کے ساتھ تنویر نقوی کی نظم ’’رنگ لائیگا شہیدوں کا لہو‘‘ تاریخ میں اپنی جگہ بنا سکے۔ قومی ترانہ تو حفیظ جالندھری کی دین ہے۔ سلامت رہے۔
مختصر بات یہ کہ شاعری کے نام پر لکھی ہوئی ہر تحریر، اَدب نہیں ہوتی ہے۔ نثری نظم کی مبادیات کو سمجھنا ہو تو زاہد ڈار، عباس اطہر، ثروت حسین اور افضال سیّد سے شروع کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ اسی طرح غزل میں خورشید رضوی اورجاوید شاہین کو امام بنائیں، پھر اس بحر میں غواصی کریں۔ نظم لکھنے کا آہنگ راشد اور مجید امجد سے حاصل کریں۔ مرثیہ گوئی میں اختر عثمان کے ساتھ چلیں۔ مختصر اور جامع نظم کے لئے حارث خلیق کا نئے موضوعات کا مشکیزہ کھولیں اور تھوڑے لکھےکو بہت جانیں۔ تقلید نہیں تخلیق چاہئے۔